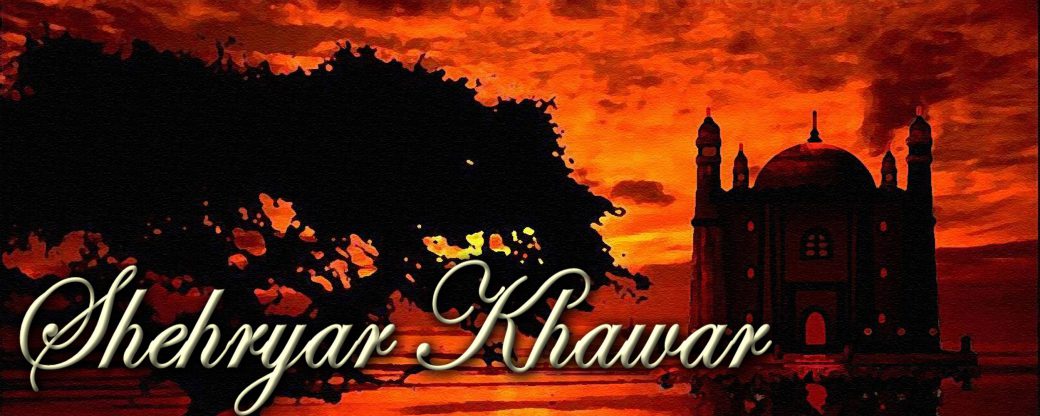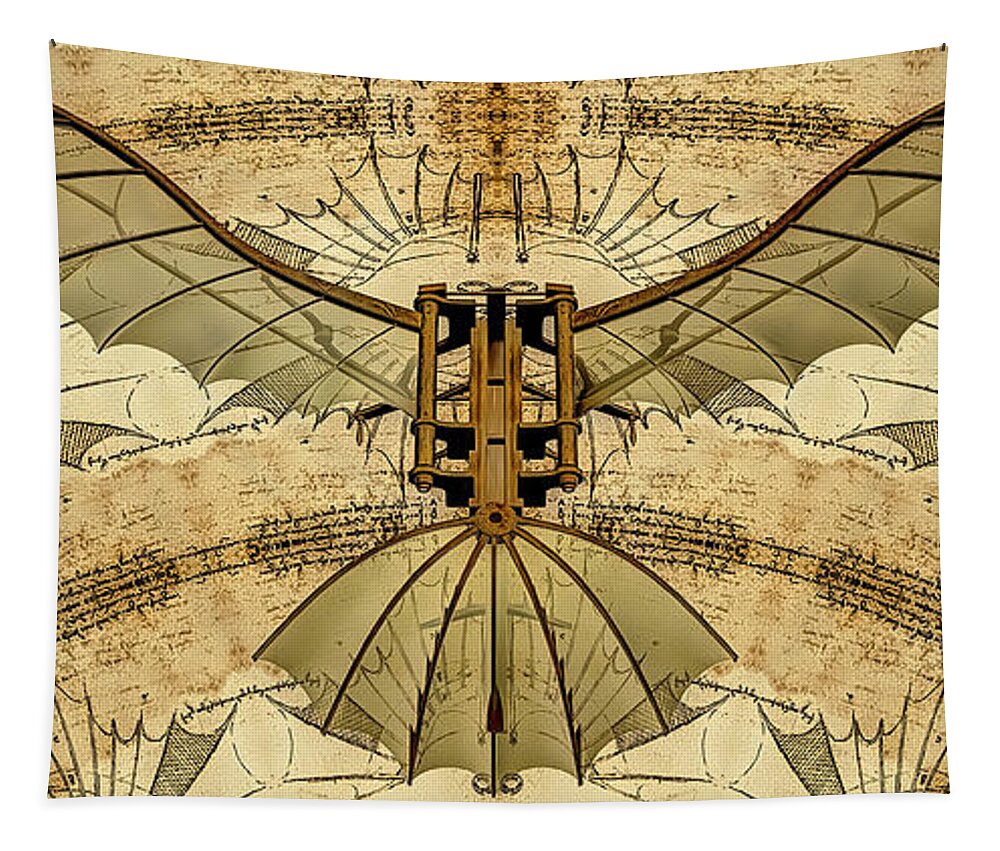تھکی ہوئی چیل نے اپنے پر سمیٹے اور گھونسلے کا رخ کرنے سے پہلے ڈوبتے سورج کی جانب آخری نظر ڈالی. اس کے پروں تلے پھیلتی تاریکی کی چادر بہت تیزی سے شہر ملتان کے سنہرے گنبد اور مٹیالے مینار نگل رہی تھی. سردیوں کی وہ گہری شام بہت اداس تھی اور اک اک کرتے ابھرتے اور ٹمٹماتے ستارے، اس شام کے حزن کی مانگ میں افشاں بھرتے نظر آرہے تھے
دن اور رات کا اختلاط بس تمام ہی ہوا چاہتا تھا. چیل نے زمین پر چمکتی روشنیوں کے ایک جھرمٹ پر نظر ڈالی جہاں سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور بھنےگوشت کی سوندھ بھی. ایک لمحے کو ڈبکی لگانے کا خیالدل میں آیا ضرور مگر پھر دور گھونسلے میں بلکتے بچوں کا سوچ کر اڑتی چلی گئ
روشنیاں رشیدخان کونسلر کی حویلی پر برقی قمقموں کی لٹکتی جھالروں کی تھیں. جشن نا صرف حالیہ الیکشن کی جیت بلکہ کونسلر کی تیسری شادی کا بھی تھا. کونسلر ساٹھ سال کا بڈھا اور تیسری دلہن کسی مشکوک خاندان کی چشم وچراغ تھی مگر تھی اٹھارہ برس کی نوخیز کلی. لہٰذا جشن کا جواز توبنتا ہی تھا. پوری حویلی جگمگ جگمگ کرتی کہکشاں بنی ہوئی تھی
دھواں حویلی کے صحن میں ایک طرف سلیقے سے لگی دیگوں تلے دہکتے انگاروں سے اٹھ رہا تھا. کھانا ختم ہوئے کچھ دیر ہوچکی تھی لیکن فضإ میں اب بھی ہرطرف بریانی اور قورمے کی اشتہاانگیز مہک رچی بسی تھی اور حویلی کی اونچی دیوار سے ٹیک لگائے فقیروں کی لمبی قطار کے صبروضبط کا امتحان لے رہی تھی
ایک جواں سال منشی جو غالباً دیگوں پر نگران مقرّر کیا گیا تھا، ایک جانب بوسکی کے سوٹ اور ریشمی واسکٹ میں ملبوس کھڑا اپنی نوکیلی مونچھوں کو تاؤ پر تاؤ دئے جا رہا تھا. اسکی توجوہ کا مرکز دیگیں کم اور کونسلر کی گاڑی سے اترتی حرم گیٹ کی طوائفوں پر زیادہ تھی جو زرق برق کپڑوں اور سونے کے بوجھ تلے دبی پریاں دکھ رہی تھیں. ان کو منشی کی آنکھ سے جھلکتی ہوس کا اچھی طرح سے اندازہ تھا مگر آج کا راجہ اندر، اکڑا کھڑا منشی نہیں بلکہ کونسلر رشید خان تھا
حویلی کے صحن میں ایک برگد کا بوڑھا درخت ٹوٹی اینٹوں کے چبوترے پر ایستادہ تھا. اس درخت کا بیج رشید خان کونسلر کے پردادے نے ڈیڑھ صدی قبل لگایا تھا. اس وقت نا حویلی تھی نا ہی خان کا سابقہ. پردادا ایک غریب موچی تھا اور حویلی کی جگہ ٹوٹا پھوٹا ایک کوٹھری کا مکان تھا جس میں جلتے چراغ سرے شام ہی بھجا دئے جاتے تھے کیونکہ تیل بہت مہنگا تھا
وقت گزرتا رہا، رشید موچی پیدا ہوا اور برگد کے درخت تلے ننگا کھیلتا بڑا ہوگیا. باپ دادا کی نسبت لڑکا بہت تیز تھا، لہٰذا اس نے جوتے سینے پر ہیروئن فروشی کو ترجیح دی. سفید پاؤڈر کے کاروبار میں کچھ ایسی برکت تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹی کوٹھری، حویلی بن گئ اور رشید موچی، رشید خان بن گیا
آج برگد کے چبوترے پر علاقے کے اکلوتے بینڈ کے ممبران براجمان تھے اور سردی سے کانپتی انگلیوں کو ایک چھوٹی سی سلگتی انگھیٹی پر تاپنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے. پیلی پڑتی سفید وردیاں جن پر پیلے ہی رنگ کے بٹن جو شاید کسی زمانے میں چمکتے پیتل کے رہے ہوں گے، کندھوں پر ٹکے پرانے باجے اور ان سے لٹکتی میلی پرانی جھالریں. غریبی اور بھوک کے منڈلاتے سایوں تلے تمام کے تمام ممبران، ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ دکھائی دے رہے تھے
ان سب سے الگ، سفید کھچڑی بال لئے اورپان کے داغ لگے گلے سڑے دانتوں میں بیڑی دبائے مدقوق بینڈ ماسٹر ایک جانب یوں اکیلا کھڑا تھا کہ جیسے کسی اجڑے مزار کا مغرور مجاور کھڑا ہو. طوائفوں کے جھرمٹ کو دیکھتے ہی ماسٹر صاحب نے ناک کے نتھنے میں گھومتی انگلی نکالی اور بوڑھی ہوس کے زور پر، آنکھوں سے پورے جھرمٹ ہی کو سموچہ نگلنے کی کوشش کی. طوائفوں نے ماسٹر صاحب کی بے وقعت ہوس پر ایک بےرحم ٹھٹا لگایا اور اندر کی جانب بڑھ گیئں.
وہاں حویلی کے صحن میں موجود ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے جوان اور پرکشش ہونے کے باوجود طوائفوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. وہ تھا پنوں مراثی
پچیس چھبیس کا سن، اونچا لمبا قد، آنکھوں میں مناسب سرمہ، تیل لگے مگر سلیقے سے جمے ہوئے بال، صاف ستھرا کرتا، سادہ لنگی اور سنہری واسکٹ، کمبخت مراثی کم اور کسی پرانی پنجابی فلم کا ہیرو زیادہ لگ رہا تھا
فضا میں تیزی سے بڑھتی خنکی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بغل میں گٹھری بنی اونی چادر نکالی اور کندھوں پر لپیٹ لی. جسم میں کچھ گرمائش محسوس کی تو وہ وہیں چبوترے پر بیٹھ گیا اور بڑی محبّت سے مخمل کے غلاف میں لپٹے ہارمونیم کو سہلانے لگا. پھر قرینے سے غلاف اتار کر ایک طرف رکھا اور ہاتھی دانت کی ملائم چابیوں کو چھیڑ کر سر کی آزمائش کی.
مہاگنی کی کالی لکڑی سے بنے ہارمونیم پر جڑی چمکتی دھات کی ایک چھوٹی سی تختی پر لکھا تھا
‘حمید مراثی اورہمنوا‘
حمید مراثی پنوں کا باپ تھا جس کا کچھ مہینوں قبل ہی انتقال ہوا تھا. ہارمونیم کی پرانی چابیوں میں باپ کا پر شفقت لمس تلاش کرتے پنوں نے اپنے ساتھیوں کے منتظر چہروں کی جانب دیکھا اور انکو تسلی دینے کے لئے مسکرا دیا
خوبصورت طوائفوں کو اندر داخل ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا مگر انکی شادی میں موجودگی کے باوجود اس مراثیوں کے ٹولے کو خاطرخواہ کمائی کی امید تھی. دراصل کونسلر کا منشی پنوں کے پرائمری اسکول کا ہم جماعت تھا اور پرانی دوستی کے ناتے اس نے پنوں سے مناسب دیہاڑی کا وعدہ کیا تھا. ہاں یہ اور بات تھی کہ پرانی دوستی کے باوجود یہ وعدہ پنوں کو پچیس فیصد کمیشن کی ادائیگی کے عیوض ملا تھا
پنوں نے منشی کی جانب نگاہ کی اور اسکی جوابی معنی خیز مسکراہٹ سے تقویت پکڑتے ہوئے آج کی محفل کے لئے بالخصوص تیار کئے گئے گیتوں کی فہرست کو دل ہی دل میں تازہ کیا
چلوبھائی مراثی پارٹی، اندر بلا رہے ہیں تم لوگوں کو’. منشی کی کرخت آواز نے پنوں کو چونکا سا دیا. اس نے نظر اٹھا کر اپنے ہمنواؤں کی جانب دیکھا جن کی سوالیہ نگاہیں اسی کی جانب لگی کھڑی تھیں
ہاں بھائی جلدی کرو. دیری ہوگئ تو کہیں مہمان ناراض نا ہوجایئں’. پنوں اپنی پارٹی کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے منشی کے ساتھ حویلی کے صحن میں لگی چھولداری میں داخل ہوگیا
اندر تو ماحول ہی کچھ اور تھا. دیسی اور ولایتی شراب کی بوتلیں گردش میں تھیں. معمولی مہمان تو کب کے جبری رخصت کردئے گئے تھے. اب وہاں صرف رشید خان کونسلر اور اس کے چیدہ چیدہ چالیس پچاس مہمان باقی رہ گئے تھے. کچھ نچلے درجے کے سیاستدان تھے، کچھ سرکاری افسر، کچھ رشتےدار اور کچھ رشیدخان کی طرح چرس اور پاؤڈر کے معزز تاجر
سب نیم دائرے میں لگے صوفوں پر براجمان تھے اور گاڑھی چھن رہی تھی. ایک طرف ڈی ایس پی صاحب ممتاز پوڈری کو اپنے مکمّل تعاون کا یقین دلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ممتاز کی بغل میں انگڑأیاں لیتی میڈم خوشبو پر، پرشوق نگاہوں سے صدقے واری ہو رہے تھے. دوسری طرف جیرا چرسی، شراب کے نشے میں ڈوبے ڈپٹی کمشنر کے منشی کا گال یوں تھپتھپا رہا تھا کہ جیسے وہ پچپن سال کا بڈھا نہ ہو بلکہ دو تین سال کا چھوٹا سا بچہ ہو. گناہوں کی تجارت اور پیسے کی چاہت نے عزت بےعزتی کا فرق مٹا دیا تھا
سامنے ایک وسیع وعریض چاندنیوں سے ڈھکا اسٹیج تھا. طوائفیں تو مہمانوں کی حیثیت کے مطابق انکی بغل گرما رہیں تھیں لہذا اسٹیج پر ایک طرف صرف بوڑھی نایکایئں بیٹھی پان چبا رہی تھیں اور ویلوں میں دیئے گئے نوٹ گن رہیں تھیں
پُنوں مراثی اور پارٹی کو اندر آتا دیکھ کر تقریباً سب ہی مہمانوں نے بدمزگی سے منہ بنایا. رشید خان کونسلر نے بھی حیرانگی سے پارٹی کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لئے کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ پیچھے ایستادہ منشی نے کندھا دبا کرکان میں کچھ سرگوشی کی. رشید خان نے مسکرا کر سر ہلایا اور واپس بیٹھ گیا. کیسے اپنے منشی کی بات نا مانتا؟ آخر کو وہ صرف منشی نہیں بلکہ اس کا نیا نویلا سالا بھی تھا
پنوں نے دور سے یہ ساری کاروائی دیکھی اور مشکور نظروں سے منشی کیطرف دیکھ کر سر ہلایا. منشی کے حوصلہ افزاء اشاروں سے اس نے ہمّت پکڑی اور اپنے ہمنواؤں اور موسیقاروں کو اسٹیج پر جگہ سنبھالنے کا اشارہ کیا
سازوں کی تاریں کھینچی گیئں، سر سیدھا کیا گیا اور پنوں نے تان لگائی. کچھ ایسا سر اور درد تھا اس کی آواز میں کہ مہمانوں نے بےاختیار ہوکر اسٹیج کی جانب دیکھنا شروع کردیا. کچھ نے تو تعریفی نگاہوں اور مسکراہٹوں سے رشید خان کی پسند کو بھی ہدیہ پیش کیا. مگر پنوں ان سب باتوں اور اشاروں سے بےخبر کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا
جس یار دے یار ہزاراں ہون
اوس یار نوں یار نا سمجھیں
جیڑا حد توں ودھ کے پیار کرے
اوس پیار نوں پیار نا سمجھیں
ہووے یار تے دیوے ہار تینوں
اوس ہار نوں ہار نا سمجھیں
بلھےشاہ
پانوھیں یار جنا وی غریب ہووے
اودی سنگت نوں بیکار نا سمجھیں
تالیاں تو بہت بجیں مگر ان میں وہ دم نہیں تھا جو پنوں چاہتا تھا. اس نے کچھ لمحے سوچا اور پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا
‘شادی کا موقع ہے. پتہ نہیں جو گانے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں’
پھر اس نے دھیمی سی مسکراہٹ سے اپنے موسیقاروں کی طرف دیکھا اور دبے الفاظ میں کچھ سمجھایا. تھوڑی دیر کے لئے تو موسیقاروں کو اپنے کانوں پر یقینن ہی نہیں آیا مگر پھر پنوں کو بضد پا کر انہوں نے اپنے ساز سیدھےکئے
فضاء میں سارنگی کا نوحہ گونجا تو حاضرین نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا
ماۓنی میں کنوں آکھاں
درد وچھوڑے دا حال نی
دھواں دھکھے میرے مرشد والا
جاں پھولاں تاں لال نی
جنگل بیلے پھراں ڈھونڈیندی
اجے نا پایو لال نی
دکھاں دی روٹی، سولاں دا سالن
آہاں دا بالن بال نی
کہے حسین فقیر نماناں
شوہ ملے تاں تھیوان حال نی
پنوں کی پردرد آواز، شاہ حسین کا پرسوز کلام، نشے اور گناہوں سے چورچور دل. پتہ نہیں کس چیز نے کس چیز پر اثر ڈالا مگر جب پنوں نے آخری تان لگا کر آنکھیں کھولیں تو حاضرین میں ہرآنکھ کو اشکبار پایا. حتکہ طوائفیں بھی اپنے زرق برق پلوؤں سے آنکھیں پونچھ رہیں تھیں
.اوئے ادھر آ مرجانیاں!’ رشیدخان کونسلر نے کھڑے ہو کر آواز لگائی تو پنوں دوڑتا چلا آیا’
‘اوئےیہ کیا گا دیا تو نے کمبخت؟’
پنوں نے رشید خان کی آنکھوں میں جھانک کر ناراضگی یا تعریف کا تعین کرنے کی کوشش کی. ‘رلا رلا کر برا حال کردیا سب کا’ رشید خان نے ہزار ہزار کے دس نوٹ پنوں کی طرف بڑھائے تو اس بیچارے کی جان میں جان آگئ. جھک جھک کر محفل کو آداب کیا اور اسٹیج پر چڑھ کر دوسری کافی شروع کی. وہ رات پنوں میراثی اورہمنواؤں کےحق میں بہت بابرکت ثابت ہوئ
محفل کے اختتام پر پنوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. دل ہی دل میں شاہ حسین کے لئے دعائے مغفرت کی اور اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا. انکی جیبیں بھریں تھیں اور چہروں پر مسکراہٹیں رقصاں تھیں. اس نے اپنے حصّے کے پیسے نیفے میں اڑسے اور ساتھیوں سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل پڑا
ملتان کی ملگجی، اداس اور دھند بھری گلیاں خاموش پڑی تھیں. بس اینٹوں پر پڑتی پنوں مراثی کے قدموں کی چاپ ہر سو گونج رہی تھی. سب لوگ اپنے گرم بستروں میں سوئے پڑے تھے. بس پنوں تھا، سردی سے کانپتے کچھ آوارہ کتے تھے اور کبھی کبھار کوئی اکیلا دکیلا چوکیدار دکھائی دے جاتا تھا. سردیوں کی رات بس بھیگ ہی چکی تھی اور دور افق پر میلا میلا اجالا ایک نۓ دن کی نوید سنا رہا تھا
ایک دودھ دہی کی کھلی دوکان کے سامنےسے گزرا تو ریڈیو پر گونجتی آواز پنوں کے کان میں پڑی. استاد امانت علی خانصاحب کی گائی غزل تھی: ‘انشاءجی اٹھو اب کوچ کرو؛ اس شہر میں جی کا لگانا کیا’
سنتےسنتے سردی پتہ نہیں کہاں غایب ہوگئی اور پنوں کے قدموں کی چاپ، تال پر گونجنا شروع ہو گئی. یہ اس کے باپ حمید میراثی کی محبوب غزل تھی. رات کی تنہائی میں سنائی دی توپنوں کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ ماضی کے ورق پلٹتے چلے گئے
‘پنوں پتّر! وےپنوں! ماں صدقے روٹی کھا کے جانا. یوںہی پکھے پیٹ نا جانا کھیلنے باہر.’
ماں کی آواز کانوں میں گونجی. پنوں چھےسال کا تھا اور چڑیا کے بچوں کی طرح گھر کے گھونسلے میں محفوظ تھا. یہ گھونسلہ اس کے ماں باپ کی محبت سے بنا ہوا تھا جس میں کسی غم، کسی مشکل کا دخل نہیں تھا
گھونسلےکی موجودگی سے بےخبر اور ماں کی التجائیں سنی ان سنی کرتا پنوں، کنچے جیب میں سنبھالتا باہر بھاگ گیا جہاں اس کے بہت سارے ہم عمر دوست اس کے منتظر تھے. جلد ہی اندرون بوہڑ گیٹ کی وہ گلی، زندگی بھرے شور اور قہقہوں سے گونجنے لگی
‘اوئے بالیو کنچے چھوڑو. پڑھو اندر بیٹھ کر.’ شیخ صاحب جو کہ اپنے گھر کے سامنے چبوترے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اتنا شور نہیں برداشت کرسکے
‘رہنے دیں شیخ صاحب. بچوں کوکھیلنے دیں. اب نہیں کھیلیں گے تو کب کھیلیں گے’
گلی سے گزرتے محلے کی مسجد کے بوڑھے امام مولوی عبدالصمد نے، مسکرا کر شیخ صاحب کو ٹوکا
آپ کی وجہ سے بچے بگڑ گئے ہیں مولانا. میری مانیں تو ان کو پکڑ کر مسجد لے جایئں اور قران پڑھایئں.’ شیخ صاحب نے نظر کی عینک اتار کر اس کے موٹے موٹے عدسے صاف کرتے ہوئے کہا
شیخ صاحب، اللہ تعلیٰ کو بچے کھیلتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ ہنستے ہیں تو آواز عرش تک جاتی ہے. ذرا باری تعالیٰ کا موڈ اچھا رہتا ہے.’ مولوی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور پنوں کا سر شفقت سے تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گئے
استغفراللہ! استغفراللہ! کیسا عجیب مولوی ہے؟’ شیخ صاحب زیرلب بڑبڑائے اور پھر سے اخبار کی سنسنی انگیز خبروں میں مگن ہوگئے
پنوں حمید مراثی اور زینت کا اکلوتا لڑکا تھا. اس لحاظ سے اسکی حیثیت کسی انمول خزانے سے کم نا تھی. حمید ذات اور پیشے، دونوں کا مراثی تھا. اس کو زندگی میں صرف تین چیزوں سے محبت تھی: پنوں، زینت اور اس کا ہارمونیم
تین افراد پر مشتمل، چھوٹی چھوٹی خوشیوں والا یہ چھوٹا سا خاندان ملتان کے قدیمی علاقے اندرون بوہڑ گیٹ کی ایک تنگ گلی میں واقع، اپنے چھوٹے سے اور ٹوٹے پھوٹے موروثی مکان میں رہتا تھا. غریب لوگ تھے. کبھی کمائی ہوجاتی، کبھی نا ہوتی. لیکن خدا سے گلہ شکوہ کئے بغیر جو روکھی سوکھی نصیب ہوتی تھی، صبروشکر کے ساتھ کھا لیتے تھے
حالات بہت گھمبیر ہو جاتے تو زینت کو بھوک لگنا ختم ہوجاتی تھی. حالات اور خراب ہوتے تو حمید کا دل بھی کھانے کو نا چاہتا. لیکن پنوں ان سب باتوں سے بےخبر کبھی کسی رات کو بھوکا نا سویا تھا
صبح سویرے جب چڑیوں کے چہچہانے اور کبوتروں کی غٹرغوں سے پنوں کی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ اسکی ماں صحن میں لگے لکڑی کے سالخوردہ تخت پر بیٹھی قران کی تلاوت کررہی ہے. اس وقت ماں کو دیکھنا پنوں کو بہت اچھا لگتا. اس کے دوپٹے میں لپٹے چہرے پر نور ہی نور ہوتا. کبھی کبھی تو پنوں کو لگتا کہ وہیں کہیں صحن میں خدا بھی بیٹھا اسکی ماں کی باتوں کا جواب دے رہا ہے. لیکن جب بھی مڑ کر دیکھتا تو صحن میں صرف سفید اور سرمئی کبوتر دانا دنکا چگتے پھر رہے ہوتے تھے
تلاوت ختم کر کے زینت قران پاک کو چوم کر ریشم کے غلاف میں ڈالتی اور برآمدے کے طاق پر احتیاط کے ساتھ سنبھال دیتی. پھر پنوں کے بستر کی طرف آکر اس کے چہرے پر پھونک مارتی اور ماتھا چوم کر اٹھنے کا اشارہ کرتی. ماں کی گرم پھونک کا حصار سارا دن پنوں کو اپنے وجود کے اردگرد گھومتا محسوس ہوتا
تھوڑی دیر میں جب ماں پھونکیں مار مار کر چولھا جلا رہی ہوتی تو حمید بھی اٹھ کر تخت پر آ بیٹھتا اور گرم نمکین پانی سے غرارے کر کے ریاض شروع کردیتا. باپ کو دیکھتے ہی پنوں فٹافٹ بستر سے اٹھتا اور بھاگ کر منہ ہاتھ دھو کر باپ کے ساتھ ریاض میں شامل ہو جاتا. حمید اسکی طرف فخر سے دیکھتا اور کبھی کبھی شفقت سے اس کا سر سہلا دیتا. کڑوے دھویئں کی اوٹ سے سرخ آنکھیں مسلتی زینت باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر مسکراتی جاتی اور دل ہی دل میں دونوں کی سلامتی کی دعایں مانگتی رہتی
رات کے سالن کے ساتھ پراٹھا اور الائچی کی خوشبو سے مہکتا چاۓ کا پیالہ پی کر پنوں اسکول کا یونیفارم پہنتا اور ماں باپ سے پیار کروا کر اسکول کے لئے رخصت ہوجاتا
کبھی کبھی پنوں کے دل میں کوئی خیال آتا تو باپ سے پوچھتا
‘ابّا! یہ روز صبح اماں قران پڑھتی ہے. تو کیوں نہیں پڑھتا؟‘
‘دیکھ بیٹے! کبھی تو نے کبوتروں کو تلاوت کرتے دیکھا ہے؟ ہر مخلوق کا اپنا اپنا عبادت کرنے کا، شکر ادا کرنے کا الگ انداز ہوتا ہے. تیری ماں تلاوت کر کے اس ذات پاک کا شکر ادا کرتی ہے اور میں گا کر’. حمید پنوں کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا جواب دیتا
‘بس تو رہنے دے اپنے فلسفے.’ زینت مسکراتے ہوئے دخل اندازی کرتی. ‘پنوں پتر! تیرا باپ بس سست ہے. اس سستی نے نماز روزہ سب چھڑا دیا’
‘سست نہیں ہوں،بس اس پاک ذات کی رحمت پر یقین ہے. ایک غریب مراثی کو دوزخ میں ڈال کر بھلا کیا کرے گا؟ اور پھر تو ہے نا نیک بخت میری بخشش کروانے کے لئے.’ حمید شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر جواب دیتا تو زینت بس مسکرا کر خاموش ہوجاتی.
سکول میں پنوں بس درمیانے درجے کا طالبعلم گردانا جاتا تھا. نا بہت اچھا اور نا ہی نالائق. ‘تومراثی کا بچہ ہے. مراثی ہی رہےگا.’ کبھی کبھی ماسٹرعلم دین تنگ آکر پنوں پر برس پڑتا
یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ پنوں کند ذھن تھا. وہ بےحد زہین تھا مگر اس کی ذہانت حساب کتاب کی بجائے سر اور تان میں پوشیدہ تھی. لمبےلمبے پہاڑے اس کو تب ہی یاد ہوتے جب وہ انہیں گا کر پڑھتا
‘اک دونی دونی، دو دونی چار’
حد تو یہ تھی کہ تھوڑی دیر درد سہنے کے بعد ماسٹر علم دین کے موٹے تیل پلائے سرخ بینت کی ضربیں بھی پنوں کو طبلے کی تھاپ کی مانند سنائی دیتی تھیں
پنوں کو مراثی کہلوانا بھی کبھی برا نہیں لگا. جب پہلی دفعہ اس کے کسی دوست نے لڑائی کےدوران اس کو مراثی که کر چھیڑا تو وہ دوڑ کر باپ کے پاس پہنچ گیا
‘ابّا! یہ مراثی کیا ہوتا ہے؟‘
‘مراثی؟’ حمید نے ہارمونیم کی چابیاں صاف کرتے چونک کر بیٹے کے سنجیدہ اور دکھی چہرے کی طرف دیکھا: ‘مراثی وہ ہوتا ہے جس کو سر اور تال سے محبت ہوتی ہے. وہ بس گاتا ہے. خود بھی خوش رہتا ہے، خدا کی مخلوق کو بھی خوش کرتا رہتا ہے اور خدا کو بھی خوش کرتا ہے’
‘لیکن ابّا! مراثی اگر اتنا اچھا ہوتا ہے تو لوگ اسے گالی کیوں سمجھتے ہیں؟’ باپ کی بات پنوں کی سمجھ میں نا آی”
‘یہ دنیا بڑی اداس جگہ ہے پتّر.’ حمید نے سر ہلاتے جواب دیا. ‘اس دنیا میں خوش رہنا بہت مشکل ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خوش رہتےہیں. اور جو خوش رہتےہیں، دنیا ان سے جلتی ہے’
‘ابّا! یہ جو ریڈیو پر بڑے بڑے استاد گاتے ہیں، یہ بھی مراثی ہیں کیا؟’ پنوں کا بڑا دل کرتا تھا کہ ایک دن وہ اور اس کا باپ مل کر ریڈیو پر سنگت کریں
‘بس پتّر یہ سب مولا کے کھیل ہیں. کسی کوعزت دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو عزت نا دے کر امتحان لیتا ہے. کسی پرکرم کر کے استاد بنا دیتا ہے اور کسی پر کرم کر کےمراثی. مگر کرتا سب پر کرم ہے.’ حمید نے مسکرا کر جواب دیا مگر بیٹے کے چہرے پر ناچتی کشمکش دیکھ کر سمجھ گیا کہ بات اس کے ننھے سے ذھن کے پلّے نہیں پڑی
‘دیکھ پتّر! یہ دنیا کے لوگ چھوٹے دل والے ہیں. تو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بھی بن گیا تو ہمیشہ تجھے مراثی ہی کہیں گے. بس تو پھرمراثی ہونے کو اپنا فخر بنا لے’. حمید نےسمجھانےکی کوشش کی
.فخر کیسے بنا لوں ابّا؟’ پنوں نے معصومیت سے پوچھا’
‘دیکھ بیٹے، مولا سر کی نعمت صرف اپنے خاص خاص بندوں کو انعام میں دیتا ہے. یہ نعمت اتنی خاص ہے کہ سارے نبیوں میں سے صرف داؤد علیہ سلام کو سر کی نعمت ملی تھی. تو پھر فخر کی بات تو ہے نا؟’ حمید نے مسکرا کر پوچھا تو پنوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور باپ کی نصیحت ساری عمر کے لئے پلّے باندھ لی
‘کون ہےبھائی؟’ اچانک ملگجے اجالے اور دھند سے اٹھتی آواز، پنوں کو ماضی سے حال میں کھینچ لائ
پنوں نے غور سے دیکھا تو آواز کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کے اپنے محلے کے بوڑھے چوکیدار رحمت کی تھی
.میں ہوں چاچا رحمت……پنوں!’ اس نے آگے بڑھ کر شناخت کروائی’
‘اچھا اچھا. اسوقت یقیناً کوئی پروگرام کر کے آرہا ہوگا تو. خیرسےآ. لیکن فجر کا وقت ہوچلا ہے، اب نماز پڑھ کر ہی سونا.’ رحمت نے شفقت سے اپنا جھریوں بھرا ہاتھ پنوں کے کندھے پر رکھتے نصیحت کی
‘ہاں جی چاچا. اب نماز پڑھ کر ہی گھر جاؤں گا’
پنوں نے محلے کی مسجد کی طرف قدم بڑھاتے جواب دیا جہاں لاؤڈ اسپیکر پر مولوی صاحب گلا کھنکھار کر اذان دینے کی تیاری کر رہے تھے. مسجد کی داخلی محراب پر نظر پڑی تو پھر یاد ماضی نے آ جکڑا
پنوں بارہ سال کا تھا اور ایک شام حمید کے ساتھ کسی پروگرام سے واپس آرہا تھا
‘چل پتر، مغرب کی اذان ہورہی ہے. تیری ماں بھی کیا یاد کرے گی، آج نماز پڑھ کر گھر چلتے ہیں. پھر سنا ہے کوئی نۓ مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں مولوی عبدالصمد کی جگہ پر. لگے ہاتھوں ان کو بھی سلام کر لیںگے.’ حمید نے پنوں کی انگلی پکڑے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا
اسوقت حال ہی میں مولوی عبدالصمد کا انتقال ہوا تھا. مرحوم بہت ہی نیک انسان تھے. نا صرف اپنی تھوڑی سی تنخواہ میں محلے کے غریب خاندانوں کی مدد کرتے بلکہ رمضان میں حمید کو نعت پڑھنے کے لئے بھی مسجد میں باقائدگی سے بلایا کرتے تھے. بڑے احسانات تھے حمید مراثی پر ان کے.
باپ بیٹا ہاتھ پکڑے مسجد کی داخلی محراب سے اندر داخل ہوئے تو حمید نے ہارمونیم کندھے سے اتار کر ایک کونے میں حفاظت سے رکھ دیا اور دونوں جوتے اتارنے لگے
‘کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ مسجد کو پلید نا کرو.’ ایک چنگھاڑ نے دونوں باپ بیٹوں کے پاؤں زمین سے جکڑ دئے. پنوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو غالباً نعۓ آنے والے مولوی صاحب تھے
گٹھا ہوا قد، سر پر عمامہ، شانوں تک ڈھلکے لمبے چنبیلی کا تیل لگے سیاہ خضاب آلود بال، مہندی لگی نارنجی مائل سیاہ شرعی داڑھی، دانتوں میں دبی نیم کی مسواک، ایک ہاتھ میں زمرد کے مصنوعی دانوں کی چمکتی تسبیح، لمبا سبز ریشمی چغہ اور سرمہ لگی آنکھوں میں خشونت کے سرخ ڈورے
‘اٹھاؤ اس شیطانی چرخے کو اور یہاں سے دفعہ ہو جاؤ. کنجرکےبچے. مراثی.’ مولوی صاحب نے انگلی سے ہارمونیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت سے کہا تو پنوں کو اللہ کے پاک گھر میں بادل گرجتے سنائی دئے
‘مولوی صاحب، یہ آپ کیا کہ رہے ہیں؟’ حمید بیچارے نے ہمّت مجتمع کرتے ہوئے احتجاج کی کوشش کی. ‘ہم تو عرصے سے اللہ کے اس گھر میں آتے ہیں. پہلے مولوی عبدالصمد مرحوم مسجد کے امام تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں روکا ہمیں
‘دماغ خراب تھا عبدالصمد کا.’ مولوی صاحب نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے جواب دیا: ‘اب میں اس مسجد کا امام ہوں. اللہ کے پاک گھر کو تم جیسے کنجروں کی وجہ سے گندا نہیں ہونے دوں گا’. مولوی صاحب نے اپنے حکم میں مزید اثر پیدا کرنے کے لئے ہارمونیم کو ایک لات رسید کی
‘چل بیٹا یہاں سے نکلیں. اب یہ اللہ کا گھر نہیں رہا، اللہ کے بندوں کا گھر بن گیا ہے. بندوں کے دلوں میں مراثیوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی’. حمید نے دکھی دل سے ٹوٹا ہارمونیم اٹھایا، پنوں کی انگلی پکڑی اور ہمیشہ کے لئے مسجد سے نکل گیا
حال میں واپس آتے ہوئے پنوں نے اپنی آنکھوں میں امڈتی نمی پونچھی اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنے پڑوسیوں کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھتا رہا. جب سب باری باری اندر چلے گئے تو اس نے ہارمونیم مسجد کے دروازے کے باہری طرف رکھا، نمازیوں کی جوتیاں ایک طرف کر کے اپنی چادر بچھائی اور نماز پڑھنے لگا
پنوں جب بھی پروگرام کر کے گھر پھنچتا تو اس کے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی سسی دروازہ کھولتی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ایسے اس کا استقبال کرتی کہ پنوں کی ساری تھکن پلک جھپکتے غائب ہوجاتی. مگراس دن ایسا نہیں ہوا
پنوں نے کافی دفعہ لکڑی کے پرانے دروازے پر دستک دی مگر کوئی کھولنے نہیں آیا. لٹکتی کنڈی پر تالا بھی نہیں لگا تھا. بیچارہ پریشان ہو کر مڑا ہی تھا کہ پڑوسیوں سے پوچھے کہ اندر سے آتی قدموں کی مخصوص چاپ نے اس کے قدم روک لئے. سسی نے دروازہ کھولا تو اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور پیشانی پر پسینے کے بیشمار قطرے موتیوں کیطرح چمک رہے تھے
پنوں نے غور سے سسی کی طرف دیکھا تو ہمیشہ کی طرح اس کی کالی گہری آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا
پنوں اور سسی کی شادی ہوئے ابھی صرف ایک سال ہی گزرا تھا. سسی، حمید مراثی کے لنگوٹیے یار افتخار مراثی کی اکلوتی بیٹی تھی اور پنوں سے عمر میں پانچ سال چھوٹی تھی. بچپن ہی سے پنوں کے عشق میں گرفتار تھی. پھر تھی بھی لاکھوں میں ایک
اونچا لمبا قد، لمبے گھنے کالے بال، بڑی بڑی کاجل کی سیاہ حدود میں قید آنکھیں جن میں زیادہ وقت شرارت ڈیرے ڈالے رکھتی تھی، سانولا سلونا رنگ اور متناسب جسم
صحیح معنوں میں گدڑی میں لعل تھی. پھر زینت کو بھی بہت پسند تھی اور وہ دل وجان سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی. مگرحساس دل والا پنوں نجانے کیوں سسی کے معاملے میں بہت کٹھور دل تھا. یا شاید وہ ہمیشہ سے سسی کو صرف ایک شوخ بچی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا
زینت سسی کے دل کے حال سے بخوبی واقف تھی مگر کیا کرتی؟ جب بھی بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا. خاوند کو کہتی تو وہ بس ہنس کرکہتا
‘نا پریشان ہوا کر زینت، جب بچوں کے دل ملنے ہوں گے، مل جایئں گے. تیرے میرے کھینچنے سے کچھ نہیں ہوگا.’ زینت بیچاری یہ سن کر چپ کرجاتی مگر دل ہی دل میں دعا ضرور کرتی
‘رب سوہنے، جیسے تو نے میرا اور حمید کا دل ملایا تھا، ویسے ہی پنوں اور سسی کا دل بھی ملا دے. میں بہاالدین ذکریا کے مزار پر دس دیئےجلاؤں گی. بلکہ اگر تو نے کچھ جلدی میرا کام کر دیا تو میں سو دیئے جلاؤں گی’
شاید قبولیت کی گھڑی تھی یا حضرت بہاؤالدین ذکریا نےزینت کی سفارش کردی ہوگی. پنوں اور سسی کے دل اس دن ملے جس دن پڑوس کے شیخ صاحب کے قل تھے
پنوں کا دل نہیں لگ رہا تھا تو وہ ماں باپ کو قلوں پر بیٹھا چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑا. لیکن گھر کے دروازے پر لٹکتا موٹا تازہ تانبے کا تالہ دیکھ کر یاد آیا کہ چابی تو وہیں ماں کے پاس رہ گئی. اب کون واپس جاتا اور ماں کو عورتوں میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر چابی لیتا
اچانک اس کو یاد آیا کہ سسی کی ماں کسی کام کی وجہ سے قلوں پرنہیں گئ تھی. لہذا پنوں نے یہ ہی فیصلہ کیا کہ جب تک حمید اور زینت گھر نہیں آجاتے، وہ قریب ہی سسی کے گھر میں آرام کرے گا. تکلّف اور شرم کی کوئی بات توتھی نہیں. دونوں گھر والوں کا آپس میں بہت آنا جانا تھا اور پھر سسی کی ماں پنوں سے اپنے بیٹوں والا سلوک کرتی تھی
‘ارے پنوں پتّر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ قلوں پرنہیں گیا؟’ پنوں افتخار مراثی کے گھر میں بےتکلّفی سے داخل ہوا تو سسی کی ماں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی.
‘گیا تو تھا اماں. پر دل نہیں لگا. پھر نیند بھی پوری کرنی ہے. رات کو ایک پروگرام میں جاناہے.’ پنوں نے سر کھجاتے جواب دیا
‘لے تو جھلّا ہے بالکل. قل بھی کوئی دل لگانے کا موقع ہوتا ہے؟’ سسی کی ماں بےاختیار ہنس پڑی لیکن پھر پنوں کو شرمندہ دیکھ کر اسے ترس آگیا. ‘جااندرجاکرسوجا. گھنٹے دو گھنٹے تک میں جگا دوںگی’
پنوں اندر گیا تو چارپائی پر ایک ریشمی بڑے بڑے پھولوں والا گہرا نیلا سوٹ بکھرا پڑا تھا. وہ اٹھا کر ایک طرف لاپرواہی سے پھینکا اور چارپائی پر لمبا لیٹ گیا. لیٹتےہی آنکھ لگ گئ. لیکن تھوڑی ہی دیر میں کھٹکا سا ہوا تو ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں
سسی نہا کر غسل خانے سے باہر نکل رہی تھی. سر پر تولیہ ڈالے بال خشک کر رہی تھی لہذا اسے پنوں کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے لئے تو پنوں پر جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا. جسم پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی. سارا بدن سنسنا رہا تھا اور گلا خشک ہو رہا تھا
‘اوئے سسی!’ بہت کوشسش کرنے پر پنوں کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی تو بیچاری سسی نے بوکھلا کر تولیہ چہرے پر سے ہٹا کر دیکھا اورپھر ‘ہائے میں مر گئ’ کہ کر واپس غسل خانے میں گھس گئ
پنوں سٹپٹاتا چارپائی سے اٹھا اور دوڑ کر گھر سے نکل گیا. سسی کی ماں آوازیں دیتی ہی رہ گئ. اس رات کھانے کے بعد پنوں نے ماں کو ایک طرف لے جا کراور شرماتے شرماتے سسی کے لئے ہاں کر دی
‘کیوں اب ایسا کیا ہوگیا کہ توسسی کے لئے اچانک مان گیا؟ اب چھوٹی بچی نہیں لگتی کیا؟’ زینت نے مسکراتے ہوئے پوچھا. سسی کی ماں نے اس کو دن کا واقعہ تو بتایا تھا لیکن سسی کی خاموشی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ پنوں اچانک سسی کے گھر سے بھاگ کیوں گیا تھا
.نہیں اماں، سسی اب بڑی ہوگئ ہے.’ پنوں نے ماں سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا’
‘اچھا؟ بڑی ہوگئ ہے؟ بھلا یہ کیسے پتا چلا میرے پتر کو؟’ زینت نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا تو پنوں نے یہ ہی بہتر سمجھا کہ وہاں سے غائب ہو جائے
زینت نے بھی بیٹے کو زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چادر سنبھالتی چل پڑی سسی کی ماں کو خوشخبری سنانے
وہ جوڑا واقعی آسمان پر بنا تھا. سسی اور پنوں کیا ملے، دونوں کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ چاند اور سورج مل گئے. ‘میری پتہ نہیں کیا نیکی کام آگئ کہ سوہنے رب نے تجھے میرے نصیب میں لکھ دیا’، سہاگ رات کو پنوں نے سسی کا گھونگٹ اٹھا کر اور دو کانپتی انگلیوں میں اسکی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا
سسی کچھ نا بولی. صرف شرما کرسر جھکا لیا اور دل ہی دل میں مسکرانے لگی. وہ غسل خانے سے باہر نکلتے ہوئے اچھی طرح جانتی تھی کہ پنوں کمرے میں موجود ہے. لیکن کیا کرتی بیچاری؟ یہ بھی نا کرتی تو پنوں شاید ساری زندگی اس کو چھوٹی سی بچی ہی سمجھتا رہتا. عشق اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے
ایک اچھی بیوی کی طرح سسی نے اپنے ساس اور سسر کے دل کی خواھش پوری کی اور شادی کے پورے تین مہینوں کے بعد حاملہ ہو گئ . پنوں کی خوشی کو تو گویا ایک دوسرا رخ مل گیا
.دیکھ لینا، لڑکی ہوگی اور بالکل تیرے جیسی سوہنی ہوگی.’ وہ سسی کو چھیڑتے ہوئے کہتا’
.نا جی نا. لڑکا ہوگا اور تیرے جیسا جوان اور بڑا گایک بنے گا.’ سسی اٹھلا کر جواب دیتی’
‘نہیں سسی. میں اپنے بیٹے کو مراثی نہیں بناؤں گا. میں اسے پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا اور بڑا آدمی بناؤں گا.’ پنوں ایک عزم کے ساتھ کہتا
‘پنوں جھلے! بڑےآدمی پڑھائی لکھائی سےنہیں، نصیب سے بنتے ہیں.’ سسی دل ہی دل میں کہتی اور اپنے خاوند کی آنکھوں میں جگمگاتے خوابوں کی روشن تعبیر کے لئے اللہ سے دعا مانگتی
‘کیا دیکھ رہا ہے ایسے بٹر بٹر؟ اندر آنا ہے یا پھر دروازے پر ہی کھڑا رہنا ہے؟’ سسی کی آواز پنوں کو حال میں کھینچ لائ
‘مجھے تو کچھ نہیں ہوا پر تجھے کیا ہوا ہے؟ پھرسے بخار تو نہیں چڑھ گیا؟’ پنوں نے فکرمندی سے سسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا
‘ہاں بخار بھی چڑھا ہے اور کھنگ بھی لگی پڑی ہے شام سے. لیکن دوا لےلی تھی. ٹھیک ہوجاؤں گی جلدی. تو فکر نا کر’. سسی خاوند کی محبت بھری نظروں سے کچھ نا چھپا سکی
‘اب تو ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آگئی ہوگی. چل آج ڈاکٹرصاحب کے پاس ہو ہی آیئں.’ پنوں نے سسی کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئےکہا
اندر جا کر پنوں نے ہارمونیم کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھا اور پھر تخت پر بیٹھی اور قران کی تلاوت کرتی ماں کے دوپٹتے سے ڈھکے سر کوچوم لیا. ماں نے محبت سے مسکرا کر بیٹے کی طرف دیکھا، قران پاک بند کیا اور پنوں کی پیشانی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری
‘کیا بات ہے پتّر؟ ماں صدقے پریشان سا لگ رہا ہے. کمائی نہیں ہوئی آج؟’ زینت نے بیٹے کے چہرے پر پھیلی پریشانی پل بھر میں بھانپ لی
‘کمائی تو بہت ہوئی اماں. بس سسی کی بیماری کا سوچ کر پریشان ہوں. بخار اور کھنگ ختم ہی نہیں ہوتے. سوچ رہا ہوں آج ڈاکٹرصاحب کے کلینک لےجاؤں.’ پنوں نے باورچی خانے میں داخل ہوتی سسی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا
‘میں نے تو بہت منع کیا تھا کہ سسی اتنا اچار نا کھا، گلا پکڑا جائے گا. مگر کہاں سنتے ہو تم دونوں میری.’ ماں نے بیٹے کو بدستور فکرمند دیکھا تو اس کادھیان بٹانے کو بولی: ‘تو پریشان نا ہو. ڈاکٹراچھی دوائی دے گا تو فوراً ٹھیک ہوجائے گی’
‘اچھا…….یہ بتا بھلا، تجھے یاد ہے کہ الله بخشے تیرا ابّا کیا کہا کرتا تھا جب تجھے اداس یا پریشان دیکھتا تھا؟’
حمید مراثی مرحوم کا ذکر آیا تو پنوں نے بےاختیار آنگن میں ایک طرف کھڑے آم کے بوڑھے درخت کی طرف دیکھا جس کے نیچے بیٹھ کر اس کا باپ ریاض کرتا تھا اور جب ریاض کرتے کرتے تھک جاتا تو بیٹے کو پاس بٹھا کر سادہ سادہ فلسفےبولتا تھا
‘پنوں پتّر! یہ جو پریشانیاں اداسیاں ہوتی ہیں نا یہ زہریلی جڑی بوٹیوں کی طرح ہوتی ہیں جن کو زمین سے سر نکالتے ہی اکھاڑ دینا چاہیے.’ حمید ہارمونیم کی چابیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا کہتا: ‘لیکن ہم ان کو اکھاڑ پھینکنے کی بجائے پانی دیتےہیں. اپنی ناآسودگی کا پانی، اداسی کا پانی، غصّے کا پانی اور لاچاری کا پانی. یہ پانی پی پی کر یہ جڑی بوٹیاں ایک دن تناور درخت بن جاتی ہیں اور ہمیں ان درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھنا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ چھاؤں بڑی زہریلی ہوتی ہے پتّر. ہمارا سارا حوصلہ اور ہمّت چوس جاتی ہے’
سسی ناشتہ لے کر آئ تو پنوں اٹھنے لگا مگر پھر ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کر رک گیا. حمید کی وفات کے بعد تین مہینوں کے اندر اندر زینت بیس سال بوڑھی ہوچکی تھی
تو اپنا خیال نہیں رکھتی اماں.’ پنوں نے پیار سے ماں کے کمزور ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا’
‘لے رکھتی تو ہوں. پھرسسی بھی تو ہر وقت کچھ نا کچھ کھانے کو لاتی رہتی ہے’. زینت نے بہو اور بیٹے دونوں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا
.تجھے ابّا بہت یاد آتا ہے نا اماں؟’ پنوں نے ماں کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پوچھا’
‘ہاں. بہت یاد آتا ہے پتّر. جب دو بندے ساتھ ساتھ اتنا عرصہ رہتے رہیں، ساتھ ہنستے ہیں، ساتھ روتے ہیں، تو ان کی جان دو سے ایک ہوجاتی ہے. ایک جان بن جاتے ہیں دونوں. اور جب آدھی جان نکل جائے تو باقی آدھی جان اکیلی رہ کر کیا کرے گی بھلا؟’ ماں نے پنوں کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا
‘ایسی باتیں نا کیا کر اماں. ابھی تو تجھے پوتے پوتیوں سے کھیلنا ہے.’ پنوں نے دکھی ہوتے ہوئے کہا.
‘اچھا نہیں کرتی ایسی باتیں. تو جلدی سے ناشتہ کر لے اور پھر تھوڑی دیر سو جا. اٹھ کر سسی کو ڈاکٹرصاحب کے پاس لےجانا.’ زینت نے ناشتے کے لئے تخت پر جگہ خالی کرتے ہوئے کہا تو پنوں کی توجوہ بھی بٹ گئ
شام کے وقت پنوں کی آنکھ کھلی تو سسی کی حالت بہت خراب ہوچکی تھی. نا صرف بخار بہت تیز تھا بلکہ کھانسی کے ساتھ خون بھی آنا شروع ہو چکا تھا. پنوں کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئ. فٹا فٹ تانگے میں بٹھایا اور قریب ہی چوک میں واقع ڈاکٹرچوہان کے کلینک میں لے گیا
ڈاکٹر چوہان سفید بالوں میں گھرے گنجےسر، سنہرے چشمے اور سفید گاؤن میں اپنے غریب مریضوں کو کسی فرشتے سے کم نا دکھائی دیتا تھا. لوگ بتاتے تھے کہ بہت لائق فائق ڈاکٹر تھا اور لندن سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے ملتان کے ایک پرائیویٹ مگر بڑے ہسپتال میں اس نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز کیا. لیکن کچھ ہی عرصے میں اپنے اردگرد جاری پیسے کی دوڑ سے تنگ آ گیا اورآخرکار نوکری چھوڑ کر اندرون بوہڑ گیٹ میں ایک چھوٹا سا کلینک کھول کر بیٹھ گیا. ساری جوانی یہ کلینک چلانے میں گزاردی
مریض کے پاس پیسے ہوتے تو لے لیتا اور نا ہوتے تو نا لیتا مگر اپنے کلینک سے علاج کے بغیر کسی غریب کو نا جانے دیتا. نیّت صاف تھی شاید اسی لئے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفاء بھی بہت رکھی تھی. کچھ لوگ تو اتنے معتقد تھے کہ صرف ڈاکٹر چوہان کے سٹیتھوسکوپ لگانے کو ہی کافی سمجھتے تھے
ڈاکٹرچوہان ساری جوانی اور ادھیڑعمری ان غریبوں کے درمیان گزارنے سے موت اور بیماری کے ہر بدصورت چہرے سے اچھی طرح واقف تھا. کبھی کبھی اس کو لگتا تھا کہ اس کا چھوٹا سا کلینک غربت اور بیماری کے درمیان واقع سرحد پر ایک اکیلی چوکی ہے اور وہ خود اس اکیلی چوکی کا اکلوتا سنتری
لیکن سسی کے معاملے میں یہ اکلوتا سنتری بےبس تھا کیونکہ ٹیسٹوں کی رپورٹ صاف بتا رہی تھی کہ سسی کو آخری اسٹیج کی ٹی بی ہے. اس بیچارے نے پوری کوشش کی کہ اپنی مایوسی کو ظاہر نا ہونے دے. پنوں کی غربت دیکھتے ہوئے نا فیس لی اور بلکہ دوائیاں بھی اپنے پاس موجود محدود سٹاک سےدے دیں
دونوں میاں بیوی کو اٹھ کر جاتا دیکھ کر ڈاکٹر چوہان نے مایوسی اور اداسی سے سر جھکا لیا. وہ ہزاروں دفعہ زہریلے خاموش سانپ جیسی اس بیماری کو غریبوں کی اس بستی میں سرسراتا دیکھ چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ مہذب دنیا میں چاہے لاکھ یہ بیماری ختم ہوگئ ہو مگر غربت میں اس بیماری کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا تھا
‘میں کس دل کے ساتھ اس کے خاوند کو بتاتا کہ اس کی بیوی اور ہونے والا بچہ دونوں کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے.’ ڈاکٹر چوہان نے دکھ کے ساتھ سوچا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اگلے مریض کو بلانے کے لئے گھنٹی بجائی
گھر واپس پھنچنے تک سسی کا بخار بہت حد تک اتر چکا تھا. پنوں بیچارہ خوش ہوگیا کہ شاید ڈاکٹر چوہان کی مسیحائی اثر کر گئ مگر کیا جانتا تھا کہ گھر پر ایک اور قیامت اس کی منتظر ہوگی
تانگہ گھر کے سامنے رکتے ہی پنوں کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوگیا. گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر صحن میں عورتیں چلتی پھرتی نظر آرہی تھیں. بیچارہ دوڑ کر اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ماں بےسدھ چارپائی پر پڑی تھی اور سسی کی ماں اس کے پاؤں کے تلووں کی مالش کررہی تھی
محلے کی کچھ اور عورتیں چارپائی کے دائیں بائیں بیٹھی اپنے اپنے مشوروں سے نواز رہی تھیں. پتہ چلا کہ پنوں اور سسی کے گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی زینت کسی کام سے گلی میں نکلی تو چکرا کر گرگئ. غالباً فالج کا دورہ تھا کیونکہ بیچاری ہاتھ پاؤں نہیں ہلا پا رہی تھی
پنوں بیچارا بری طرح سے بوکھلا گیا. پہلے سسی اور اب زینت. شاید پریشانیوں اور مصیبتوں نے گھر کا دروازہ تاڑ لیا تھا. اس نے جلدی جلدی سسی کو اس کی ماں کے سپرد کیا اور اسی تانگے پر ماں کو گود میں لے کر نشتر ہسپتال لے گیا. تین دن زینت ہسپتال میں رہی اور پنوں نے اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا. خدمت میں کوئی کمی نا آنے دی. دوائیاں، شربت ہرچیزپوری کی. سارا جمع جتھا ماں پر لگا دیا. مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہسپتال میں تیسری رات زینت خاموشی سے دم توڑ گئ. شاید حمید کے جانے کے بعد واقعی اس دنیا میں اس کا جی نہیں لگ رہا تھا
زینت کے مرنے سے نا زمین پھٹی نا آسمان شک ہوا لیکن پنوں کو لگا کہ جیسے اس کے سر سے چھاؤں چلی گئ ہو. ماں کے مرنے کے بعد تو دھوپ بھی تیز لگتی ہے
ماں کو باپ کی قبر کے برابر دفنا کر واپس آیا تو پنوں ماں کے تخت اور اس پر رکھی رحل سے لپٹا ساری رات بلک بلک کر روتا رہا. سسی بیچاری پہلے تو پنوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی لیکن جب ناکام ہوگئ تو وہیں تخت پر بیٹھ کر خود بھی رونے لگی. اس کو شاید اندازہ ہو چلا تھا کہ پنوں نا صرف اپنی یتیمی پررو رہا تھا بلکہ سسی کی آنے والی موت کے سامنے بھی بے بسی کے آنسو بہاء رہا تھا. لیکن سسی بھی کیا کرتی. وہ مرنا نہیں چاہتی تھی. وہ جینا چاہتی تھی، پنوں کے لئے اور اپنی آنے والی اولاد کے لئے
زینت کی ناگہانی موت کے بعد پنوں کے لئے زندگی ایک کڑا امتحان بن کر رہ گئ. کبھی کبھی اس کو لگتا کہ جیسے سسی کسی جھولے کی سواری کررہی ہے. کبھی اوپر جاتی اور کچھ عرصہ اچھی صحت اور خیریت کےساتھ گزرجاتا لیکن پھر یکایک نیچے آتی اور کئی کئی دن بیماری اور کھانسی کی نظر ہوجاتے. یوں اس کی اچھی صحت والےدن بھی پنوں کو برے دنوں کے پیامبر لگتے
پنوں کیلئے سسی کا خیال رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا. خاص طور پر بیماری والے دنوں میں تو پنوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس طرح دیہاڑی کمانے گھر سے باہر نکلے. سسی کی اپنی ماں بیمار رہتی تھی لیکن پھر بھی بیچاری پنوں کے پیچھے بیٹی کا خیال رکھتی
پروگرام کرنے کے بعد پنوں تھکا ہارا واپس آتا اور اپنی ساس کو فارغ کر کے خود سسی کی نگہداشت کا ذمہ اٹھاتا. اس کو بچوں کی طرح نہلاتا دھلاتا، صاف کپڑے پہناتا، کھلاتا پلاتا اور پھر گرم تیل سے رگڑ رگڑ کے سسی کے بیمار جوڑوں سے درد کھینچ نکالنے کی کوشش کرتا
سسی بیچاری ٹک ٹک دیکھتی رہتی کہ کیسے اس کا خاوند ماں بن کر اس کا خیال رکھ رہا ہے. اور اس وقت تو واقعی پنوں بلکل ماں بن جاتا جب سسی بہت بیمار ہوتی اور وہ اس کو گود میں لے کر لوریاں سناتا. سسی اس کی درد بھری آواز سنتی اور سنتے سنتے نجانے کب نیند، درد اور بےچینی کی جگہ لےلیتی
کبھی کبھی جب شدید بخار کی حالت میں اسے موت کے فرشتے کے تاریک پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی تو بیچاری خوف سے پنوں کو آواز دیتی اور اسے گانے کے لئے کہتی
‘پنوں تو گاتا کیوں نہیں؟ دیکھ یہ مجھے تجھ سے چھین کر لے جائے گا
پنوں اس وقت تک گاتا رہتا جب تک موت کے فرشتے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ہارمونیم کے سروں میں گم نا ہو جا تی. جب تھک جاتا تو وہیں سسی کے پہلو میں گر کر اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹےسو جاتا. لیکن ان تمامتر محبتوں اور کوششوں سے کوئی فائدہ نہیں ہورہا تھا. اب جب پنوں سسی کی طرف دیکھتا تو اس کو اپنی حسین وجمیل بیوی کی بجائے ایک سایہ دکھائی دیتا جو ڈھلتی دھوپ کے ساتھ بقاء کی آخری جنگ لڑ رہا تھا
ڈاکٹروں اور حکیموں سے مایوس ہونے کے بعد تمام لاچار انسانوں کی طرح پنوں کے پاس بھی فقط خدا کا سہارا بچا تھا. بیچارا پانچوں وقت کی نماز پڑھتا اور دن رات خدا سے رو رو کر سسی کی زندگی اور صحت کی دعایں مانگتا. ملتان کے ہر بزرگ کے سالانہ عرس پر حاضری دیتا، رات رات بھر کافیاں گاتا رہتا اور صبح سوجے ہوئے گلے کے ساتھ پھر سسی کی خدمت میں جت جاتا
کبھی درویشوں اور ملنگوں کے ساتھ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچتا اور تب تک ناچتا رہتا جب تک کہ زمین اس کے پیروں سے رستے خون سے سرخ نا ہو جاتی. لیکن تمام دعاؤں کا، مزاروں پر حاضریوں کا، گانے کا، ناچنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سسی گھلتی چلی گئ. پنوں کو لگتا تھا کہ جیسے سسی سمندر کی ریت ہے جس کو وہ جتنی مضبوطی سے بھی اپنی مٹھی میں تھامنے کی کوشش کرتا، وہ مٹھی سے پھسل کر گرتی چلی جاتی
سسی، پنوں کی زندگی کی سڑک کا پہلا اور آخری سنگ میل تھا جس کے پتھر بہت تیزی سے بھربھرا رہے تھے. اس کو یقین ہوچلا تھا کہ بہت جلد سسی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس تلخ حقیقت کا کیسے سامنا کرے
سسی کی حثیت پنوں کی زندگی میں رنگوں اور سروں کی طرح تھی کہ جن کے بغیر زندگی بےرنگ اور خاموش ہوجاتی. اس کو اپنی ماں کی بات یادآتی اور لگتا کہ وہ اور سسی یکجان ہو چکے ہیں
پھرایک دن غریبوں کی اس بستی میں رمضان شریف آگیا، مذہبی جوش وخروش اور نیک کاموں سے بھرپور تمام مسلمانوں کے لئے خوشی کا مہینہ. لیکن بیچارے مراثیوں کے لئے رمضان اور محرم میں کوئی فرق نہیں تھا. دونوں کمائی سے مکمّل محرومی کے مہینے تھے. اور غریبوں کے لئے تو ویسے بھی نا صرف رمضان بلکہ عیدالفطر بھی پریشانیوں اور محرومیوں کا پیغام لاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر دن غریبوں کے بچوں کےدل ٹوٹتے ہیں
لہٰذا باقی مسلمان بھائیوں کے برعکس مراثی برادری کے دل رمضان کی آمد پر ڈوبنا شروع ہو جاتےتھے. رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے اپنے طبلوں اور سازوں کو تالا لگا کر رکھ دیتے اور پیٹ کس کر روزے رکھنے کی تیاری شروع کردیتے. پورے ایک مہینے کا مسلسل روزہ
پنوں بیچارا توسسی کے خیال میں لگا تھا. اس کو بالکل رمضان کی آمد کا پتہ نہیں چلا. پتہ چلا تو تب جب محلے کی مسجد سے بھونپو بجنا شروع ہوئے اور باہر گلی سے مبارک مبارک کی آوازیں آنا شروع ہوگیئں. اس بیچارے کیلئے آمدنی کے سب ذریعے یکدم ختم ہوگئے. اس نے دوستوں سے، سسی کے ماں باپ سے، سب سے ادھار مانگا اور تب تک ادھار لیتا رہا جب تک وہ دینے کے قابل رہے. پھر ایک دن نوبت یہاں تک آن پھنچی کہ اس کو اپنے مرحوم باپ کا ہارمونیم بھی بیچنا پڑا
نا صرف وہ ہارمونیم حمید میراثی کی آخری نشانی تھی بلکہ کبھی کبھی تو پنوں کو لگتا کہ اس کے باپ کی روح کا ایک حصّہ اس ہارمونیم کے کسی گوشے میں مقیم ہے. لیکن مرتا کیا نا کرتا. ہارمونیم اس کو سسی سے زیادہ تو عزیز نہیں تھا. لہٰذا دو ہزار روپے کے عیوض بیچنا پڑا. اس بیچارے نے دو ہزار روپے جیب میں ڈالے، باپ کی روح سے دل ہی دل میں معافی مانگی اور ہارمونیم پر لگی سلور کی پلیٹ پر پیار سے آخری دفعہ ہاتھ پھیر کر چلا آیا. لیکن وہ دو ہزار روپے بھی مشکل سے صرف ایک ہی ہفتہ نکال پائے
پھر ایک دن جب پنوں سوتی سسی کی پیشانی پر تیل سے مالش کر رہا تھا تو اس کو محلے کی مسجد کے لاؤڈسپیکر پر نعت گانے کی آواز آئ
‘یا نبی! یا نبی! یثرب کے والی! غریبوں کے والی! یتیموں کے والی!’ نعتیہ محفل اپنے عروج پر تھی
پنوں کو یاد آیا کہ باپ کسی زمانے میں مسجد میں رمضان میں نعتیں پڑھتا تھا تو محلے کے متخیر حضرات کچھ نا کچھ مدد کر ہی دیا کرتے تھے
پہلے تو مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں سوچ کر کچھ ڈرا لیکن پھر سوئی سسی کی طرف دیکھ کر ہمت پکڑی، وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا.
ابھی بیچارہ جوتے اتار کر داخلی محراب سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ مولوی صاحب کی کرخت آواز نے پاؤں پکڑ لئے
‘کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟’ ایک تو مولوی صاحب کی آواز میں کرختگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور دوسرا منبر پرسبز ریشمی چغے میں ملبوس بیٹھے وہ مولوی کم اور خلیفہ وقت زیادہ لگ رہے تھے
رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ نعت خواں اور منہ سے دف بجاتے ان کے ہمنوا مولوی صاحب کی آواز سنتے ہی یوں خاموش ہوگئے کہ جیسے کسی نے ان کا سوئچ آف کردیا ہو
.جی وہ میں نعت گانے آیا ہوں.’ پنوں بیچارے نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے کہا’
‘برخوردار! نعت گائی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے. اور کیا وقت قیامت سر پر آ کھڑا ہوا ہے کہ اب کنجر اور میراثی مسجدوں میں نعتیں پڑھا کریں گے؟’
یہ که کر مولوی صاحب نے حاضرین محفل کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا تو پوراہال ‘توبہ! توبہ! استغفراللہ! استغفراللہ!’ کےنعروں سےگونج اٹھا اور پنوں الله کے بندوں کے جذبہ ایمانی کے ڈر سے الله کے گھر سے نکل گیا. پھر محراب کے باہر فقیروں کو قطار میں بیٹھے دیکھا تو خود بھی چادر آگے پھیلا کر وہیں بیٹھ گیا.
آدھے ایک گھنٹے کے بعد محفل اختتام پذیر ہوئی تو باہر نکلتے حاضرین میں سے کچھ نے پنوں کی چادر پر بھی پانچ دس کے کچھ نوٹ پھینکے
‘کیا کرتے ہو مؤمنو؟ کنجروں کو خیرات یا صدقہ دینا جائزنہیں’
یہ سن کر پنوں نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے سر پر کھڑے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، چادر پر بکھرے نوٹ سمیٹ کر مسجد کے باہر لگے چندے کے ڈبے میں ڈالے اور گھر کی طرف دکھی قدموں سے چل پڑا
ابھی پنوں گھر کے دروازے پر لگی کنڈی کھول ہی رہا تھا کہ اسے اندر سے سسی کے بری طرح کھانسنے کی آواز آئ. وہ دوڑ کر اندر پھنچا تو دیکھا کہ سسی زمین پر گٹھری بنی پڑی کھانس رہی تھی اور اس کےہونٹ، تھوڑی اورقمیض کا اگلا حصّہ سیاہی مائل خون سے داغدار ہو چکا تھا
پنوں نے جلدی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اتنی احتیاط سے بستر پر لٹایا کہ جیسےوہ کانچ کی گڑیا ہو. زبردستی تھوڑا پانی پلایا تو سسی کی کھانسی کو کچھ آرام آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں. پنوں نے آرام اور احتیاط سے سسی کا منہ صاف کیا، کپڑے تبدیل کئے اور سسی کی ماں کے گھر سےکچھ کھانے پینے کا پتا کرنے نکلنے لگا
‘پنوں! وےپنوں! کہاں جارہا ہےمجھے چھوڑ کر؟’ سسی کی کمزور اور سہمی ہوئی آواز نے پنوں کے پاؤں پکڑ لئے
‘کہیں نہیں میری جان. میں نے کہاں جانا ہے بھلا؟ میں یہیں ہوں نا، تیرے پاس.’ پنوں نے جھک کر سسی کی جلتی پیشانی چوم کر کہا
‘آج گانا نہیں سنائے گا اپنی سسی کو؟ دیکھ آج آخری بارسنا دے. پھرکبھی تنگ نہیں کروں گی.’ سسی نے اپنے کمزور ہاتھ پنوں کے چہرے پر پھیرے تو اسکی آنکھیں ڈبڈبا گیئں
اس نے آہستگی سے اپنے آپ کو سسی سے الگ کیا اور ایک خالی گھڑا لے کر وہیں سسی کے بستر کے پاس زمیں پر بیٹھ کر گانے لگا
‘ماۓنی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نی
دھواں دھکھے میرے مرشد والا، جاں پھولاں تاں لال نی
جنگل بیلے پھراں ڈھونڈیندی، اجے نا پایو لال نی
دکھاں دی روٹی، سولاں دا سالن، آہیں دا بالن بال نی
کہے حسین فقیر نماناں، شوہ ملے تاں تھیوان حال نی’
پتہ نہیں پنوں کب تک روتا رہا اور گاتا رہا. فجر کی اذان کان میں پڑی تو گھڑا ایک طرف رکھ کر اٹھا اور سسی کو دیکھا. اس کی کھانسی کو آرام تھا، اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا. بلکہ تڑخے ہوئے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ کا شائبہ ہورہا تھا. پنوں کو اس پر بہت پیار آیا
جھک کر پیشانی چومی تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑی تھی. اس نے چھاتی پر ہاتھ لگایا تو وہاں بھی خاموشی اور سکوت کا راج تھا. پنوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دو نمکین قطرے پھسلے اور سسی کی بند آنکھوں میں جذب ہوگئے
پنوں نے سسی کے بےجان سر کے نیچے تکیہ درست کیا، اس کے بکھرے بال کانپتی انگلیوں سے سنوارے اور اس کے برفیلے جسم کو اپنی چادر سے ڈھک دیا. پھر اپنے آنسو صاف کئے، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور کھڑا ہوگیا
‘اللہ واکبر‘
صبح عید کا دن تھا. سورج ہنستا ہوا باہر نکلا. نیلے آسمان پر چکر لگاتی چیل نے نیچے دیکھا تو رنگ ہی رنگ نظر آئے. بچے کھلکھلاتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے. کچھ اپنے باپوں کی انگلیاں تھامے مسجد نماز پڑھنے جارہے تھے. ہر گھر سے میٹھا اور خوشبودار دھواں اٹھ رہا تھا اور شہر ملتان کے برج اور مینار سونے کی طرح چمک رہے تھے
افتخارمراثی نماز کے لئے گھر سے نکلا تو سسی کی ماں نے بھی بیٹی کی خبر لینے کو سوچا. دروازہ اندر سے بند تھا. بہت دیر کھٹکھٹاتی رہی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئ. بیچاری نے گھبرا کر مدد کے لئے آواز بلند کی تو مسجد سے نکلتے نمازی اکٹھے ہوگئے اور افتخارکی سربراہی میں مل کر دروازہ توڑا گیا
اندربالکل خاموشی تھی. سسی بستر پر مری پڑی تھی اور پنوں سجدے میں بےجان. جب زندہ تھے تو دو جسم اور ایک جان تھے. اب مردہ تھے تو صرف دو جسم تھے اور جان اس کے حوالے ہو چکی تھی جو محبت کا سب سے بڑا اور سب سے سچا قدردان ہے
#urdu #story #love #life #death #God #compnaionship #soul #music #musician #merasi #religion #tolerence #kindness #understanding #rigidity #discrimination
‘